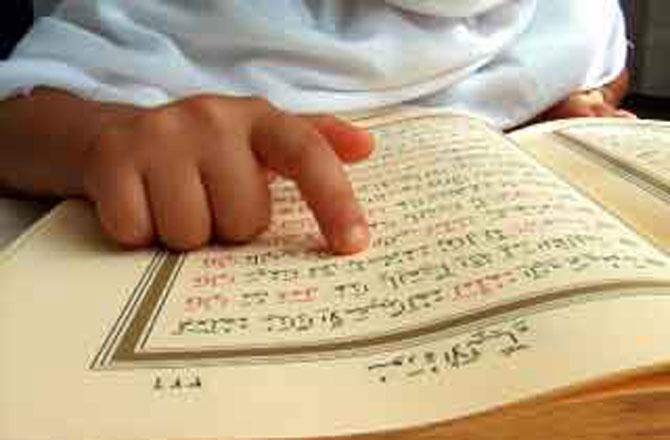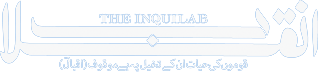قرآن پاک میں مختلف معاملات کیلئے مختلف الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ کہیں اس کو عہد کہا گیا ہے، کہیں عقد اور کہیں وعدہ۔ لیکن یہ تمام الفاظ جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں ان سے مراد اور مقصود یہی ہے کہ معاملات کی درستی ہمیشہ پیش نظر رہے
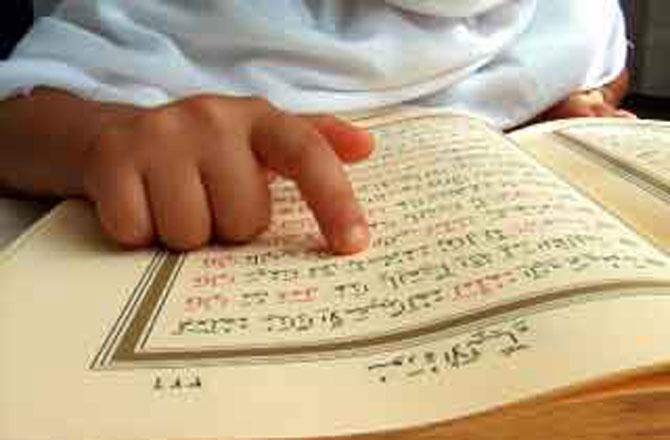
قرآن شریف ۔ تصویر : آئی این این
انسان فطرتاً مدنی الطبع واقع ہوا ہے اور اس کے وجود اور ضرورتوں کا تقاضا ہے کہ وہ ایک جماعت یا ایک معاشرے میں مستقل طور پر مل جل کر رہے۔ اگر وہ اس تعلق کو برقرار نہ رکھ سکے تو اس کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ انسانیت کی پوری تاریخ اور خود فطرت ِ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان معاشرے سے جدا یا بے تعلق نہ کبھی رہا ہے اور نہ کبھی رہ سکتا ہے۔ وہ پیدا ہی ایک معاشرے کے اندر ہوتا ہے اور اسی میں پرورش پاتا اور پروان چڑھتا ہے۔ پھر اپنی فطری صلاحیتوں کا استعمال اور اپنی شخصیت کا پورا اظہار بھی وہ معاشرے کے اندر کرتا ہے۔ اس کا علم اور اس کی عقل، اس کی عادتیں اور اس کے خیالات، اس کے احساسات اور اس کی زبان، غرض شرافت کا پورا سرمایہ اسے معاشرہ ہی سے ملتا ہے اور معاشرہ ہی میں صرف ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انسانی زندگی عبارت ہی معاشرے کے تعلق سے ہے۔ جو شخص معاشرہ سے بالکل بے تعلق ہو اسے ہم کسی صورت انسان نہیں کہہ سکتے۔
زندگی کی اچھائی اور برائی کا دارومدار بھی اسی بات پر ہے کہ ایک فرد نے معاشرے سے جو تعلقات قائم کئے ہیں وہ کس قسم کے ہیں؟ یعنی اس کے تعلقات اگر معاشرے کے ساتھ اچھے اور خوشگوار ہیں اور ان کی بنیاد نیکی اور بھلائی پر قائم کی گئی ہے تو اس کا نفع خود اس کی ذات کو یہ پہنچے گا کہ اس کی زندگی بھی زیادہ بہتر، زیادہ خوشگوار اور زیادہ پاکیزہ ہوگی، اور اگر معاشرے کے ساتھ اس کے تعلقات برے اور خراب ہیں اور ان کی بنیاد گناہ اور بدی پر رکھی گئی ہے تو اس کے نقصان اور اس کے غیرصحتمند اثرات سے خود اس کی زندگی بھی محفوظ نہیں رہے گی اور وہ (انسان) ہمیشہ رنج و غم اور مصیبتوں کا شکار رہے گا۔
معاشرے سے تعلق قائم کرنے کو ہم اپنی دینی اصطلاح میں معاملہ کہتے ہیں ۔ جب یہ تعلق نیک اور اچھی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے تو اس کو ’’حسن معاملہ‘‘ یا نیک برتاؤ سے تعبیر کرتے ہیں ، اور اگر اس کے برعکس ہوتا ہے تو اس کو بدمعاملگی یا برے برتاؤ سے موسوم کرتے ہیں۔
قرآن حکیم کی تمام تعلیمات کو جن تین بڑے عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے تیسرا عنوان ان ہی معاملات پر مشتمل ہے ۔ لیکن پہلے دو عنوانات میں جہاں عقائد اور عبادت کی وضاحت کی گئی ہے اور ان کی اہمیت بتائی گئی ہے وہاں بھی ان کو پرکھنے کے لئے اصل کسوٹی معاملات ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اسلام جو آخری اور مکمل دین ہے، اس کی اصل وجہ بھی قرآن پاک کی یہی تعلیمات ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں۔ دنیا میں آج تک نہ جانے کتنی صورتیں معاملات کی پیدا ہوئیں اور مٹ گئیں، لیکن ان میں سے کسی معاملے کی کوئی صورت یا کوئی نوعیت ایسی نہیں پیدا ہوئی جسے قرآن مجید کے بیان کردہ ’’حسن معاملہ‘‘ کے جواب میں پیش کیا جاسکے۔
معاملے کے لئے کم از کم دو فریقوں کا ہونا ضروری ہے لیکن اسلام نے اس بارے میں جس باریک بینی کا اہتمام کیا ہے اس کی کوئی نظیر کسی دوسرے معاشرتی نظام میں نہیں ملتی۔ یہاں ایک فرد کے معاملات کی ابتداء خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، یعنی معاملات کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک فرد معاشرے کے ساتھ کس طور پر معاملہ کرتا ہے ، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک فرد کا معاملہ خود اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے ؟ ان تمام معاملات کو جب ایک فرد خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے اور ان حدود کا پوری طرح لحاظ رکھتا ہے جو قرآن پاک نے متعین کی ہیں تو اس کے اس عمل کو ’’حسن معاملہ‘‘ کہا جاتا ہے۔
قرآن پاک میں مختلف قسم کے معاملات کے لئے مختلف الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ کہیں اس کو عہد کہا گیا ہے، کہیں عقد اور کہیں وعدہ۔ لیکن یہ تمام الفاظ جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں ان سے مراد اور مقصود یہی ہے کہ معاملات کی درستی ہمیشہ پیش نظر رہے۔
عرف ِ عام میں عہد کے معنی قول و قرار کے لئے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں اس کی حقیقت بہت وسیع ہے۔ وہ اخلاق، معاشرت، مذہب اور معاملات کی ان تمام صورتوں پر مشتمل ہے جن کی پابندی انسان پر عقلاً ، شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً فرض ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ مختصر سا لفظ
انسان کی بہت سی عقلی، شرعی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی فضیلتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لئے قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے اور مختلف حیثیتوں سے آیا ہے۔ سورۂ مومنون میں ان کو کامل ایمان والوں کی خاص صفتوں میں شمار کیا گیا ہے:
’’اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔‘‘ (المومنون:۸)
دوسری جگہ سورہ معارج میں جہاں جنتی مسلمانوں کے اوصاف کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہاں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ … ’’وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔‘‘
بہرحال پاس، عہد اور حسن معاملہ کی ابتداء خود اپنی ذات اور اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کے جائز حقوق ادا کرے اور جو ذاتی صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں ان میں خیانت نہ کرے بلکہ ان کو بھی صرف جائز کاموں میں استعمال کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو حسن معاملہ کے پہلے ہی مقام پر شکست کھا جاتا ہے اور اس سے یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ معاملات کی کسی دوسری منزل میں کامیاب ہوسکے گا۔
باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:
’’اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے (دفاعاً) نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ بیشک اللہ کسی (ایسے شخص) کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔‘‘ (النساء:۱۰۷)
یعنی جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے کیونکہ دل و دماغ کی قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں، ان پر بے جا تصرف کرکے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا، اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت میں رکاوٹ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اس ظالمانہ خصلت کو پوری طرح اپنالیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت اور معصیت کے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ گویا انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے یا برے کام انجام دیتا ہے ان تمام میں وہ سب سے پہلے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اپنے ساتھ جس حسنِ معاملت پر اس کو پابند کیا تھا اس سے درگزر کرتا ہے۔
معاشرے میں رہ کر انسان دوسروں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اور خیانت اور بددیانتی کرتا ہے اور اپنی اس بدمعاملگی کو صرف دوسروں کے لئے نقصان دہ سمجھتا ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ جو برائی اور نقصان وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے وہ برائی اور نقصان اسی کی جانب لوٹ آتا ہے اور اس درجہ بڑھ چڑھ کر لوٹتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوجاتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے:
’’ اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بیشک اللہ تم پر مہربان ہے۔‘‘ (النساء:۲۹)
یعنی دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دنیا میں اس سے نظام تمدن خراب ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج سے دوسروں کا مال ہضم کرجانے والا آدمی بھی نہیں بچ سکتا اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے اس لئے وہ ہم کو ایسے کاموں سے منع کررہا ہے جس میں ہماری اپنی بربادی ہے۔
دنیا کی تمدنی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ چوری، رشوت خوری، خیانت اور بے جا نفع اندوزی نے جس معاشرے میں بھی جڑ پکڑی وہ معاشرہ بالآخر برباد ہوکر ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نظامِ معاشرت میں ان خرابیوں کی روک تھام کے لئے قانون اور حکومت کی قوت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کو ہلاکت اور بربادی سے بچایا جاسکے۔
اسلام نے ان خرابیوں کی روک تھام کے سلسلے میں سیاسی قوت کے علاوہ عقیدے کی قوت کو بھی استعمال کیا ہے اور اس طرح اس امر کا پورا اہتمام کیا ہے کہ انسانوں کے درمیان معاملات، خیر اور خوبی کی بنیادوں پر قائم ہوسکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
’’اور وعدہ پورا کیا کرو، بیشک وعدہ کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ناپ پورا رکھا کرو جب (بھی) تم (کوئی چیز) ناپو اور (جب تولنے لگو تو) سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہ (دیانت داری) بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے (بھی) خوب تر ہے۔‘‘ (الاسراء: ۳۴۔۳۵)
اس بات سے ہر شخص اچھی طرح واقف ہے کہ تمدنی تعلقات کا ایک بہت بڑا حصہ معاشی معاملات اور لین دین سے متعلق ہوتا ہے اور اس لین دین کے معاملات کو درست رکھنے کے لئے قانون یا رسم و رواج کے ذریعے سے جو وزن یا پیمانہ مقرر ہوجاتا ہے وہ درحقیقت ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کی پابندی بیچنے اور خریدنے والے پر قرض ہوتی ہے۔ اسی لئے اس آیت ِ پاک میں اس معاہدہ کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ثابت ہوجاتا ہے کہ عہد کے لئے زبانی قول و قرار کی ضرورت نہیں بلکہ عرفِ عام کے سارے مسلمات سوسائٹی کے قول و قرار ہیں اور معاملات کی درستی کے لئے ان کی پابندی ضروری ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ’’اے ایمان والو! (اپنے) عہد پورے کرو۔‘‘ (المائدہ:!)
اس آیت طیبہ میں عقود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جمع ہے عقد کی اور اس کے معنی گرہ یا گرہ لگانے کے ہیں اور اس سے مقصود لین دین اور معاملات کی باہمی پابندیوں کی گرہ ہے۔ اصطلاح شریعت میں یہ لفظ ہر قسم کے معاملات کے لئے بولا جاتا ہے۔
امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:
’’اس قول میں تمام عقد مثلاً عقد بیع، عقد شرکت، عقد یمین، عقد نذر، عقدصلح اور عقد نکاح داخل ہیں۔ اس آیت کا اقتضاء یہ ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو عقد اور جو عہد قرار پا جائے اس کے مطابق دونوں پر اس کا پورا کرنا واجب ہے۔‘‘
حسنِ معاملہ اور حسنِ عہد کے سلسلے میں حضور نبی اکرم ﷺ سے بھی کئی احادیث مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ؐ کا ارشاد ہے: ’’حسنِ عہد ایمان سے ہے۔‘‘
ایک دوسری حدیث میں حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا : ’’جس میں عہد نہیں اس میں ایمان نہیں۔‘‘
یعنی اس قول و قرار کو جو بندہ خدا سے کرتا ہے یا بندہ بندے سے کرتا ہے، پورا کرنا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنا ہے اور اسی کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اب جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا یا اپنے معاملات کو حسن و خوبی سے انجام نہیں دیتا وہ دین کی روح سے محروم ہے۔
اسلامی معاشرے میں فرد کی خوش معاملگی کے اس معیار کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں تو ہمیں خود اپنی خامیاں نظر آجائیں گی ، معلوم ہوگا کہ ہم اس بنیادی اسلامی کسوٹی پر کس حد تک پورا اُترتے ہیں۔ آج کی اصل ضرورت یہی ہے کہ ہم معاملات میں اپنی زندگی کو قرآنی ہدایات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں ۔ اسی میں ہماری دینی اور دنیاوی فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔