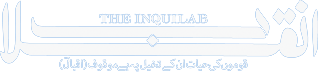مراٹھی ادب کو مکند راج گیانیشور ، تکارام ، ایکناتھ جیسے سنت شاعروں کی زبان وراثت میں ملی تھی، تو پنت یعنی عظیم شاعروں کا فن بھی روایت سے آیا تھا۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے مراٹھی ادب کے موضوعات ، زبان، اسلوب میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنے لگی۔

مراٹھی ادب پڑھنے اور اس سے محبت کرنے والوں کی آج بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تصویر: آئی این این
مراٹھی میں بیسویں صدی کی پانچویں دہائی سے نئے ادب کا بول بالا شروع ہوا۔ یہ نیا ادب مہاراشٹر کے اعلیٰ طبقے کی تہذیب کا حصہ تھا۔ ظاہر ہے اس طبقے میں عوام کے لئے کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ نئے ادب کا رخ ہیئت پسندی کی جانب زیادہ تھا۔ مراٹھی ادب کو مکند راج گیانیشور، تکارام، ایکناتھ جیسے سنت شاعروں کی زبان وراثت میں ملی تھی، تو پنت یعنی عظیم شاعروں کا فن بھی روایت سے آیا تھا۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے مراٹھی ادب کے موضوعات، زبان، اسلوب میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنے لگی۔ پہلے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ، عظیم وراثت کا احساس، مراٹھی ادب پر دوسری زبانوں کے ادب کی طرح حاوی تھا مگر آزادی کے بعد ملک میں سبھی سطح پر مایوسی ہی حاصل ہونے لگی تو اس کا عکس ادب اور دوسرے فنون لطیفہ پر پڑنا ضروری تھا۔ بیسویں صدی کے آخری چالیس سال میں ہندوستان کو کئی مورچوں پر لڑائی لڑنی پڑی۔ دانشوروں، ادیبوں، فنکاروں نے ان سبھی کا گہرا مطالعہ کیا۔ اپنی اپنی ذہنی اور جذباتی تربیت کے مطابق ان باتوں کو جذب کیا۔ ان کی وجہ سے آگے چل کر ہونے والے اثرات کی تہہ کا جائزہ لیا اور اس کا جو ردّعمل ان کے دل و دماغ پر ہوا اسے اپنی تخلیق میں رقم کیا۔ الگ الگ سوچ، نظریے اور احساس سے پنپتا مراٹھی ادب دوسرے علاقوں کے ادب کے ہمراہ ہوتا رہا جو آج بھی منزل کی طرف تیز کچھ سست قدم چل رہا ہے۔
ہندوستان آزاد ہونے کے بعد مراٹھی شاعری میں نئی صبح کی آمد کی خوشیاں چھلکنے لگیں۔ صدیوں بعد آج دیکھی پہلی خوشگوار صبح کا ماحول پیدا تو ہوا مگر دھیرے دھیرے ’تھا انتظار جس کا یہ وہ سحر تو نہیں ‘ اس بات سے سبھی واقف ہونے لگے۔ اسی مایوسی میں ابھرے شاعری میں کئی سوال، اور انیل نے کہا سبھی دیپ کیسے مدھم ہوچلے؟ تو سریش بھٹ نے ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا :
ہوتا ہوتا کال راترزھالی
ارے پنھا آیشیا چا پیٹوا مشالی
(صبح ہوتے ہوتے کالی رات ہوگئی
چلو پھر سے زندگی کی مشعلیں جلائیں )
آزادی کے بعد کے چالیس سال مراٹھی شاعری میں بڑا شور و غل رہا۔ مراٹھی شاعری کی سبھی اصناف میں شاعری ہوتی رہی۔ پابند شاعری سے لے کر آزاد نظم، نثری نظم تک کی عمدہ تخلیق ہوتی رہی۔ مادھوراؤ پٹوردھن کے چھندو رچنا، نامی علم عروض کی کتاب کی وجہ سے اردو کا آہنگ اور عروض مراٹھی میں داخل ہوا۔ انگریزی اور یورپ کی شاعری مراٹھی میں بڑے پیمانے پر منتقل ہوئی۔
جمالیات سے حقیقت پسندی کی اور مراٹھی شاعری کا رجحان دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا۔ ایک لہر قومی یک جہتی کی تحریک سے جڑی تھی تو دوسری طرف سمجھ میں تبدیلی لانے کا منشا رکھنے والی شاعری پنپ رہی تھی۔ اس دور میں گ۔ دی۔ ماڈگلکر کا گیت رامائن نامی مسلسل نغموں کا مجموعہ سب سے زیادہ مقبول رہا۔
اس دور میں جمالیاتی شاعری ’بورکر‘ کررہے تھے۔ ان کی شاعری میں زندگی سے بے پناہ محبت، نیچر کی خوبصورتی کا احساس، الفاظ کی تازگی اور موسیقیت (غنائیت) تھی۔ برعکس کسماگرج کی شاعری میں سوشل اویئرنیس، عوام کے جذبات کی گونج، اصول پسندی اور پرامیدی ابھر آتی ہے۔ شرت چندر، مکتی بودھ کی نظموں پر سوشلزم کا اثر صاف نمایاں ہوتا ہے۔
بی ایس مرڈھیکر مراٹھی شاعری کے میر کارواں کہلاتے ہیں۔ کیشوسوت نے آزادی سے پہلے رومانٹک احساس کی شاعری کی تو مرڈھیکر نے جنگ عظیم کے بعد کی مشینی زندگی کی حقیقت سے واقف کرایا۔ شاعری کے بارے میں جو روایتی خیالات تھے، اسٹرکچر کے جو دائرے تھے، اور موضوع کی نسل در نسل چلی آرہی ذہنیت تھی، اسے توڑ پھوڑ دیا، شاعری کے بے معنی الفاظ، مبالغہ، علامتی اسلوب کو توڑ مروڑ دیا، انسان کی بے بسی اور تنہائی کو صحیح سُر دیا۔ اظہار خیال کے لئے مراٹھی کی آسان بحریں استعمال کیں، ایک نیا احساس مراٹھی ادب کو بخشا۔ ان کی شاعری پلے نہیں پڑتی، ایسا نقادوں کا کہنا تھا۔ اصول پسند آدرش وادی اعلیٰ طبقے نے اس نئی شاعری کو ناپسند کیا، مگر اب تک ان کی شاعری کا اثر دکھائی دیتا ہے۔
گرندیکر، باپٹ، پاڈگاؤنکر اس تری وینی نے شاعری ترنم میں سنا کر عوام تک پہنچائی اور کاویہ واچن کی روایت قائم کی تھی۔ گیان پیٹھ انعام یافتہ کسماگرج اور ونداکرندیکر یہ دو شاعر مراٹھی میں ہوئے۔ کرندیکر اجتماعیت کے زیراثر شاعری کرتے رہے مگر ۱۹۵۹ء سے اس نظریے کے اثر سے باہر نکلے۔ پراثر الفاظ، ہیئت پسندی اور جذبات کی گہرائی ان کی شاعری کی شناخت ہے۔ خواتین شاعروں میں اندراسنت کا نام سب سے اہم ہے۔ ’’ہاتھیوں کے دانت پر کی گئی نقاشی ہے ان کی شاعری‘‘ یہ رائے ہے بزرگ نقاد گنگادھر گاڈگل کی۔ مراٹھی شاعری کی روایت سنت گیانیشور سے شروع ہوتی ہے۔ دور حاضر کے احساسات کا اظہار کرنے کی قابلیت اس زبان میں ہے مگر زبان میں تجربہ ہونا ضروری ہے۔ مرڈھیکر کے بعد انگریزی الفاظ مراٹھی شاعری میں آنے لگے۔ ادبی احساس کی روایت آج کی سکڑتی ہوئی دنیا میں اپنے آپ آفاقیت پارہی ہے۔ جدید یورپین اور امریکن ادب کا اثر لئے بنا ہماری قابلیت ِ اظہار میں اضافہ ہونا ناممکن ہے، یہ رائے تھی جدید مراٹھی شاعروں کی جن میں دلیپ چترے، سدانند ریگے، انیردھ کلکرنی کے نام سرفہرست تھے۔ رومانیت کی مخالفت کرنے والی اور اینٹی رومانٹک پروسیس سے پیدا ہونے کا دعویٰ کرنے والی بیشتر جدید مراٹھی شاعری پھر سے جمالیاتی لہر سے جاملتی ہے۔ پوشی ریگے، آرتی پربھو، مہانوراور شنکر رامانی ان شاعروں کی نظمیں اسی قسم کی مثالیں ہیں۔
مراٹھی کے والمیکی ماڈگلکر نے نئے دور کے شاعروں سے مخاطب ہوکر کہا تھا ’’تم لوگوں کی نظمیں اور عالموں کی اس پر کی ہوئی تنقید یہ دونوں باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر دانشوروں کو ان نظموں میں کچھ دکھائی دیتا ہو تو انہیں (ان نظموں کے معنی) بار با پڑھنے والوں کو سمجھانا چاہئے۔ ‘‘آج کی رمز آمیز شاعری عوام کی سمجھ کے باہر ہے۔
(مضمون کی دوسری قسط آئندہ ہفتے ملاحظہ کیجئے)